داروغہ کا لڑکا
ریل کی سیٹی
ہندوستان کی سرزمین پہ سولہ اپریل 1853 کے دن پہلی بار ریل چلی تھی۔ جس طرح پل بنانے والے نے دریا کے اس پار کا سچ اس پار کے حوالے کیا ، اسی طرح ریل کے انجن نے فاصلوں کو نیا مفہوم عطا کیا۔ اباسین ایکسپریس ، کلکتہ میل اور خیبر میل صرف ریل گاڑیوں کے نام نہیں بلکہ ہجر، فراق اور وصل کے روشن استعارے تھے۔
اب جب باؤ ٹرین جل چکی ہے اور شالیمار ایکسپریس بھی مغلپورہ ورکشاپ کے مرقد میں ہے، میرے ذہن کے لوکوموٹیو شیڈ میں کچھ یادیں بار بار آگے پیچھے شنٹ کر رہی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے ریل میں بیٹھ کر تو کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر خود سے کی ہیں۔ وائی فائی اور کلاؤڈ کے اس دور میں، میں امید کرتا ہوں میرے یہ مکالمے آپ کو پسند آئیں گے۔
سدھار کی بستی پہلے شہر سے باہر بستی تھی۔ آبادی کا سیلاب آیا تو اسے بھی نگل گیا اور اب یہ شہر کا حصہ ہے۔ جانے والے سرداروں نے سدھار کی شام کو اپنے دل سے اور سدھار کے نام کو اپنی ذات سے جوڑ لیا ہے۔
لائل پور سے نکلتی ریل، سمن آباد کے ریلوے اسٹیشن سے ہوتی ہوئی سر شمیر کو چھوتی ہے۔
یاد کے گاؤں میں ایک پکی اینٹوں والا گھر تھا۔ دس سال ہونے کو آئے مگر سلیٹی رنگ کا وہ نلکا اب بھی اسی طرح آنگن کی اینٹوں کو سیراب کر رہا ہے۔ سیمنٹ لگے کمروں کے اس مکان میں ایک فوجی اپنی نوکری پوری کر کے زمینوں کو لوٹ آیا تھا اور دوسرا چھٹی پوری کر کے زمین کی حفاظت کرنے جا رہا تھا۔ سر کو جھکائے زمیندار، بچوں کے افسر ہونے کا خاموش نوحہ پڑھتا تو گندم کا ہر یتیم خوشہ اس کے ساتھ ماتم کرتا تھا۔
سرشمیر کا پرانا نام دھوپ سڑی تھا، پھر اسے صاحباں کی آہ لگ گئی اور اب یہ بستی ویر شہمیر کے نام سے آباد ہے۔ سن سینتالیس میں دادا جی غلام احمد لدھیانہ سے لٹے پٹے آئے تو گاؤں والوں نے سرشمیر کی دو سراؤں میں سے ایک انہیں دلوا دی۔
سرائے کیا تھی، بس چار کمرے، بڑا سا احاطہ اور درمیان میں ایک درخت۔ یوں تو اس پرانے کیکر تلے بیٹیوں کی باراتیں بھی اترتیں اور بڑے بوڑھوں کے جنازے بھی اٹھتے مگر جب بیساکھی آتی تو کینیڈا اور ہندوستان کے کچھ لوگ آ کر پہروں اس کی چھاؤں میں بیٹھے رہتے۔
جب محرابوں والے بڑی اینٹ کے دروازے تکتے تکتے آنکھوں میں ’’کچھ‘‘ پڑ جاتا تو کھڑے ہو کر اجازت مانگ لیتے۔ جاتے وقت یہ سردار بے حد تشکر سے دادا جی اور ان کے ہیڈماسٹر بیٹے کا ہاتھ تھام کر دیر تک شکریہ ادا کرتے جنہوں نے ان کے پرکھوں کی نشانی یوں سنبھال رکھی تھی۔ دادا جی نے سچ میں سرائے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ عمر کے سو سال پار کرنے کے با وجود وہ مغرب کی نماز سرائے جا کر ہی پڑھا کرتے تھے۔
2008 میں دادا جی گزر گئے تو سرائے بھی ویران ہو گئی۔ جس دن چاچا ہیڈ ماسٹر نے لڑکوں کے کہنے پہ پرکھوں کی نشانی گرانے کے لئے مزدور منگوائے اور پچھلی دیوار پہ ہتھوڑے کی پہلی ٹھوکر پڑی، اس دن بہت سے پرندے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیکر سے اڑ گئے۔
اس ساری سڑک پہ ہجرت کا تارکول اور یاد کی بجری پڑی ہے۔ کہیں آنے والوں نے شناخت قائم رکھنے کے لئے جالندھر ارائیاں اور جواہر سنگھ جیسے گاؤں آباد کر لئے ہیں اور کہیں جانے والے اپنا ٹھیکری والا اور جگت پور یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ آگے چلیں تو رکھ برانچ اور گوگیرہ برانچ نے تاش کے پتوں کی مانند آپس میں گاؤں بانٹ رکھے ہیں۔
جڑانوالہ سے نکلتی ٹرین تاندلیانوالہ پہ رکتی ہے۔ بوٹی کے نام پہ آباد یہ شہر درخت کی طرح ٹھہر گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسا سکوت ہو تو ناز خیالوی جیسا شاعر پیدا ہوتا ہے اور گورکھ دھندا جیسی نظم تخلیق پاتی ہے۔
تھوڑی دور تک تو پٹڑی سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی ہے مگر پھر سڑک نہر کا ہاتھ تھام کر دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ اسی راستے میں ستیانہ کا قصبہ اور آوا گت کا گاؤں ہے۔
جڑانوالہ کے دوسری طرف ایک سورج کنڈ بھی ہے جو فرید پور، ہریانہ والے سورج کنڈ جیسا بالکل نہیں ۔ دونوں کے درمیان چند صدیوں کی مسافت ہی نہیں ایک لکیر بھی ہے ، جسے سر بجیت اور ثنا ء اللہ کے خون سے اکثر سیراب کیا جاتا ہے۔
فیصل آباد اور جڑانوالہ کی دو لکیریں صرف ریل کی پٹڑیاں نہیں بلکہ دو شہروں کی ان گنت کہانیاں ہیں۔
پہلی کہانی ڈجکوٹ کی ہے، جسے پرانے وقتوں میں ڈچ کوٹ کہا جاتا تھا۔ جہاں نیا شہر آباد ہے وہاں پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ ڈچ کوٹ کے لفظی معانی تو قلعے میں آباد شہر کے ہیں مگر اب یہاں نہ تو قلعہ کا سراغ ملتا ہے اور نہ شہر کا نشان۔
یوں تو آج کل شہر کے اجاڑے کو فوج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مگر ڈجکوٹ کا یہ شہر کئی لشکروں کے ستم کی کہانی سناتا ہے۔ سکندر نے اجاڑا تو چند گپت موریہ نے بسایا اور ہمسایوں نے برباد کیا تو سوریوں نے آباد کیا۔ کہیں کہیں محمد بن قاسم کا نام بھی لیا جاتا ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب شہزادہ یہیں سے گرفتار ہوا تھا۔ انگریز یہاں پہنچے تو انیسویں صدی ڈھلنے والی تھی۔ راج کے افسروں نے اسپتال کھولا، چوکی ڈالی اور ڈاک گھر بنا کرحکومت کرنا شروع ہو گئے۔
دوسری کہانی ایک چھوٹے شہر کے بڑے آدمی کی ہے۔
یہ 1901 کا سمندری تھا جب داروغہ بشیسور ناتھ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ داروغہ جی تو ملازمت کے سلسلے میں شہر شہر گھوما کرتے مگر بچہ اپنے دادا کیشو مل سے کہانیاں سنتا اور بولیاں بولتا۔
بشیسور ناتھ کی تبدیلی ہوئی اور گھر والے لائل پور سے پشاور کے ڈھکی منور شاہ والے مکان میں آئے تو لڑکا بھی لاہور سے ہوتا ہوا پشاور کے ایڈورڈ کالج میں پہنچ گیا۔ بات اب سکول کے زمانے کی راس لیلا سے آگے بڑھ چکی تھی ۔ تھیٹر کا شوق اسے کالج کے ڈرامہ کلب تک لے آیا تھا، جہاں ایک مقامی استاد ایک انگریز خاتون کی محبت میں گرفتار تھا۔
پروفیسر جے دیال کی محبت اسٹیج کے مکالموں سے لفظ لفظ اٹھتی تو پردے کے پار بیٹھی نورا رچرڈ کے دل پہ بوند بوند اترا کرتی۔ جب اوتھیلو، دس دیمونا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا تو یہ جذبات جے دیال کے دل سے نکلتے اور جب پورشیا، باسانیو کے ہجر میں رہتی تو نورا کی آنکھیں بھی بے ساختہ بھر آتیں۔ مگر پردے کے آگے یہ سب احساسات کسی اور کے فن کی آرتی اتار رہے تھے۔ پھر ایک دن داروغہ کا لڑکا خالہ سے قرض لے کر بمبئی چلا آیا۔
بابو راؤ اسے یہیں ملا تھا۔ وہ ایک مشہور فلمی نقاد تھا اور لڑکا ایک قلاش فنکار۔ سیٹ کے باہر بابو راؤ پٹیل نے اس پہ گہری نظر ڈالی اور اس سے بھی گہرا طنز کیا۔
’’فلم کے فیتے پہ ایسے کرخت پٹھانوں کی کوئی جگہ نہیں جو خود کو فنکار سمجھتے ہیں‘‘
لڑکا بولا؛ ’’بابو راؤ، اس کرخت پٹھان کو اگر یہاں کوئی جگہ نہ ملی تو بھلے سات سمندر تیر نے پڑیں، یہ پردیس جائے گا اور ادا کار بنے گا۔‘‘
مگر ایسا نہیں ہوا اور پرتھوی راج سات سمندر تیرنے سے پہلے ہی بڑے فنکار بن گئے۔ پشاور سے بمبئی اور بمبئی سے کلکتے کے بیچ بیچ ہی ہندی اور ہندکو بولنے والے اس پٹھان کا نام فلم اور تھیٹر کی کامیابی کی ضمانت بن گیا۔
سہراب مودی کی سکندر اعظم سینما کی زینت بنی تو یونانی نین نقش والا سکندر، سمندری کے پرتھوی راج کی چھب میں ڈھل چکا تھا۔ پہلی بار پورس کو ہیرو بنا کر دکھانے والی یہ فلم جنگ عظیم دوم کے دوران قومیت کے موضوع پہ شاہکار ثابت ہوئی۔
بہت سال گزرے مقابلے کے امتحان میں تاریخ کے پرچے کی تیاری کے دوران میں نے بابا سے پوچھا کہ اکبر کیسا دکھتا تھا۔ بابا نے الماری کی زنبیل سے پچاس سال پرانی خان آصف کی مغل اعظم نکال کر مجھے تھما دی۔
’’آوارہ‘‘ میں جج صاحب کا کردار ادا کرنے والے دیوان بشیسور ناتھ سے راج نیتی کے سمیر پرتاپ والے رنبیر کپور تک یہ خاندان، پانچ نسلوں سے فیتے کے راستے لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہیں۔
1994 میں پرتھوی تھیٹرز کی گولڈن جوبلی منائی گئی تو ان کی خدمات کے اعتراف میں ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ ٹکٹ پہ کمپنی کا نشان اور پرتھوی راج کی تصویر تو تھی مگر نام نہ تھا۔ کپور خاندان کا ماننا تھا کہ کچھ چہروں کو ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اتنا وقت بیت جانے کے با وجود اب بھی جوہو کے کپور گھرانوں کے ہون میں پشاور کی مٹی جلائی جاتی ہے اور سو سال پورے ہونے کے باوصف آج بھی ہندی سینما کی تاریخ اس جملے سے شروع ہوتی ہے؛
’’یہ 1901 کا سمندری تھا جب داروغہ بشیسور ناتھ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔‘‘
is blog ko Hindi-Urdu mein sunne ke liye play ka button click karen [soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/93024135" params="" width=" 100%" height="166" iframe="true" /]










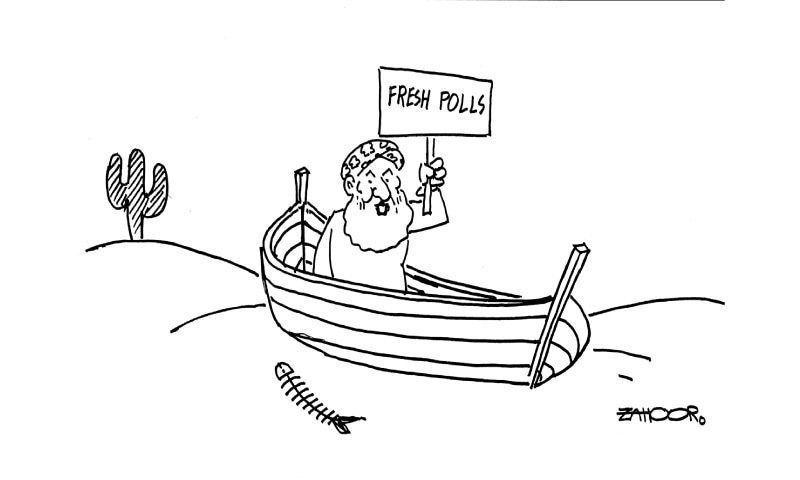
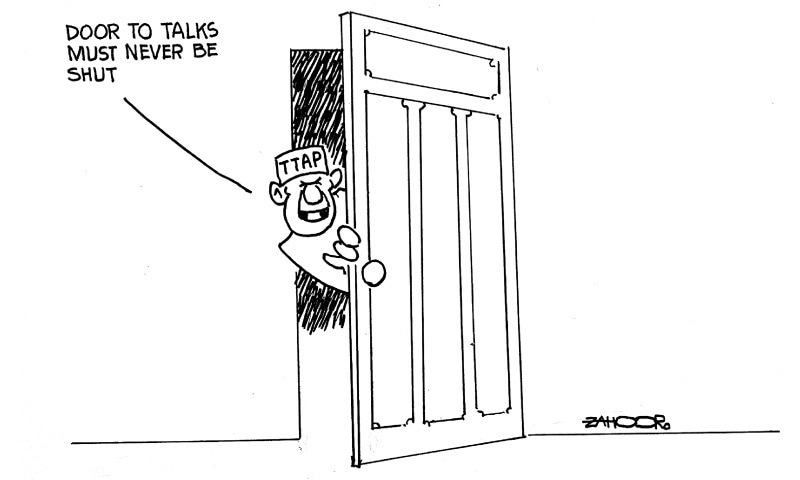





 لائیو ٹی وی
لائیو ٹی وی
تبصرے (4) بند ہیں