کراچی جو اِک شہر تھا (پانچواں حصہ)
یہ اس سیریز کا پانچواں بلاگ ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصہ پڑھیں۔
80ء کی دہائی میں ملیر تک آنے والی بسوں اور ویگنوں کے چند ہی پبلک ٹرانسپورٹ رُوٹس تھے جو روزانہ یہاں کے باسیوں کو شہر کے مختلف خطوں تک لے جاتے اور وہاں سے واپس لاتے تھے۔
ان گاڑیوں میں سب سے اہم کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن (کے ٹی سی) کی بس نمبر ’15A‘ تھی جو کھوکھراپار مہران ہوٹل اسٹاپ سے چلتی تھی اور چمن کالونی، ندی کنارا، کھوکھراپار نمبر 6، 5، 4، 3، 2 اور 1 کے اسٹاپوں پر رکتی ہوئی سعود آباد، ملیر ٹنکی، لال مسجد اور کالا بورڈ سے ہوکر شارع فیصل کے راستے صدر جاتی تھی۔
مجھے یاد نہیں کہ صدر تک اس کا کرایہ کتنا تھا کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اور صرف 30 پیسے دیا کرتے تھے۔ دوسری 15 نمبر بس تھی جو سعود آباد گرلز کالج کے سامنے سے چلتی تھی اور لیاقت مارکیٹ، جناح اسکوائر، محبت نگر اور ملیر سٹی سے ہوتی ہوئی صدر جاتی تھی۔ 15 نمبر روٹ کی یہ بس لوگوں کے لئے اتنی اہم تھی کہ جس جگہ سے یہ نیشنل ہائی وے چھوڑ کر اندر ملیر کی طرف مڑتی تھی، اس اسٹاپ کا نام ہی ’ملیر 15‘ پڑگیا۔


آج اس بس کو بند ہوئے 2 عشرے گزر گئے ہیں لیکن وہ اسٹاپ آج بھی ملیر 15 ہی کہلاتا ہے۔ ان دو کے علاوہ کے ٹی سی کی ایک اور بس ’9C‘ بھی تھی جو صدر سے آتے ہوئے ملیر ہالٹ سے اندر سیکیورٹی پرنٹنگ پریس والے روڈ پر مڑ جاتی تھی اور ماڈل کالونی سے گزرتی ہوئی ملیر کینٹ تک جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے لیے ایک ’15E‘ نمبر کی بس بھی چلی تھی جو شاید لیاقت آباد اور سائٹ ایریا کی طرف جاتی تھی۔
ان سرکاری بسوں کے علاوہ کچھ پرائیویٹ بسیں بھی مہران ہوٹل سے لی مارکیٹ جاتی تھیں۔ کراچی کی یہ رنگ برنگی، دولہن کی طرح سجی ہوئی بسیں عام طور پر بلوچ ٹرانسپورٹرز کی ملکیت ہوا کرتی تھیں۔ لی مارکیٹ اور کھوکھراپار کے درمیان چلنے والی ان بسوں کا روٹ نمبر ’51A‘ ہوتا تھا، جبکہ اسی طرح کی ایک اور بس ’52A‘ بھی تھی جو لی مارکیٹ سے قائد آباد جاتی تھی۔
’51A‘ ڈرگ روڈ پر پہنچ کر شارع فیصل کو چھوڑ دیتی تھی اور سی او ڈی والے روڈ (جو بعد میں راشد منہاس روڈ کہلایا) پر مڑ جاتی تھی اور ڈرائیو اِن سنیما، ڈالمیا، اسٹیڈیم، لیاقت ہسپتال، ٹی وی اسٹیشن، نیو ٹاؤن، سینٹرل جیل، پیر کالونی، تین ہٹی، لسبیلہ اور گاندھی گارڈن سے ہوتی ہوئی لی مارکیٹ تک جاتی تھی۔ رات گئے لی مارکیٹ سے ملیر واپس آنے والی یہ بس جب ڈرائیو اِن سنیما کے پاس سے گزرتی تو اندھیرے میں سنیما کی کئی منزلہ بلند اوپن ایئر اسکرین پر چلنے والی فلم کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کھڑکیوں سے اپنا پورا سر باہر نکال لیا کرتے تھے۔
ان بسوں کے پیچھے سیڑھی بھی ہوا کرتی تھی جس سے چڑھ کر لوگ بس کی چھت پر بیٹھ کر ہوا کھاتے ہوئے بھی سفر کرتے تھے۔ ان بسوں کے لیے عام طور پر ’ٹھٹے والی بس‘ کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی کیونکہ یہ ٹھٹھہ جانے والی بسوں کی طرح ہوتی تھیں۔ ان کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر عام طور پر مکرانی بلوچ ہوتے تھے۔ یہ کنڈیکٹر چلتی بس سے لٹک کر کرتب دکھانے کے انداز میں چھت پر چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھے مسافروں سے ٹکٹ وصول کرکے اسی طرح بازی گری کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں نیچے واپس بھی آجاتے تھے۔
ہر بس کے اندر چھت میں تیز آواز والے کئی اسپیکر نصب ہوتے تھے جن پر عام طور سے انڈین گانے بجتے رہتے تھے۔ کوئی باذوق ڈرائیور ہوتا تو محمد رفیع، کشور کمار، طلعت محمود، مکیش، ہیمنت کمار اور لتا کے پرانے گانے چلاتا تھا، ورنہ عام طور پر نئے بے ہنگم اور بیہودہ گانے ہی بجائے جاتے تھے۔
میں آج تک جن پرانے انڈین گانوں سے واقف ہوں، وہ زیادہ تر انہی بسوں میں سفر کے دوران ہی سن سن کر یاد ہوئے تھے۔ وہ سارے گانے مجھے آج بھی یاد ہیں۔ جیسے
- یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں،
- کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ،
- بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے،
- لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے،
- چودہویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو،
- سہانی رات ڈھل چکی نا جانے تم کہاں ہو،
- میرے سامنے والی کھڑکی میں اک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے،
- تیرے بنا زندگی سے شکوہ تو نہیں،
- میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا،
- تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی،
- میری یاد میں تم نا آنسو بہانا،
- یہ رات یہ چاندنی پھر کہاں سن جا دل کی داستاں،
- ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا،
- کہیں دیپ جلے کہیں دل،
- جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
- یونہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے،
- آج پھر جینے کی تمنا ہے آج پھر مرنے کا ارادہ ہے،
- نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں مگر کیا کریں اپنی راہیں جدا ہیں۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ آئے ہائے، کہاں گئے وہ دن؟
ان ٹھٹے والی بسوں کے علاوہ ایک پیلی بیڈ فورڈ ویگن ’R‘ بھی ہوتی تھی جو کھوکھراپار ڈاکخانہ سے صدر جاتی تھی۔ اس کا کرایہ تو نسبتاً مہنگا ہوتا تھا، مگر اسٹاپ کم ہوتے تھے۔ یہ جیل روڈ اور مزار قائد کے راستے صدر جاتی تھی۔ اس ابتدائی دور میں غالباً یہی 5 یا 6 بسیں تھیں۔
پختون ڈرائیوروں والی مزدا منی بسوں اور کوچوں کا دور ابھی عام نہیں ہوا تھا۔ میں اسکول کبھی سائیکل پر جاتا تھا اور کبھی ان بسوں میں بیٹھ کر۔ رش اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ خطرناک طریقے سے دروازوں پر لٹک لٹک کر بھی سفر کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ حادثات بھی دیکھے۔ دروازے پر لٹکے کسی مسافر کا کسی موڑ پر بس کی تیز رفتاری کے باعث ہاتھ چھوٹ جاتا اور وہ دور جا کر گرتا، ہاتھ پاؤں تڑواتا یا پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر ہی جاتا۔ ہمارا گھر چونکہ آخری اسٹاپ کے قریب تھا اس لیے مجھے اکثر جگہ مل جایا کرتی تھی۔

اس زمانے میں ہم بڑے بوڑھوں کی زبان سے عام طور پر ایک لفظ ’چودہویں صدی‘ بہت سنا کرتے تھے۔ ہر بُری بات اور اکثر بُرے واقعات کا تعلق چودہویں صدی سے جوڑا جاتا کیونکہ روایات کے مطابق یہ صدی اچھی نہیں تھی۔ ہم اس دور کی نئی نسل تھے اور چودہویں صدی کے بھی آخر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں شک کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ نہ جانے کب کیا گل کھلا دیں۔ میری عمر 14 سال کی ہوئی ہوگی کہ چودہویں صدی ختم ہوگئی اور 20 نومبر 1979ء کے دن پندرہویں صدی کا آغاز ہوگیا۔
یکم محرم 1400 ہجری کو منگل کا دن تھا۔ ہم اسکول میں ہی تھے کہ اچانک ایک ایسی خبر آئی کہ پورے عالم اسلام کا دل دہل گیا۔ پندرہویں صدی ہجری کے پہلے ہی دن ایک عرب گروپ نے مسجد الحرام پر حملہ کرکے زائرین کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہوگئی اور لڑکوں نے باہر سڑک پر آکر احتجاجی مظاہرہ شروع کردیا۔ جس کو جو چیز ہاتھ آئی وہ لے کر کسی نہ کسی چیز پر پل پڑا۔ لڑکے نعرے لگاتے شور مچاتے ڈنڈے بجاتے سڑک پر پیدل ہی سعود آباد کی طرف چل دیے۔ اس مشتعل جلوس کے ساتھ میں اس دن پہلی مرتبہ گھر تک پیدل آیا۔ اگلے 2 ہفتے تک پوری دنیا میں یہی موضوع رہا، حتیٰ کہ سعودی فوج نے پاکستانی کمانڈوز کی مدد سے خانہ کعبہ کو ان شرپسندوں سے آزاد کروا لیا۔

انہی دنوں ایک اور مشہور عالم واقعہ ’اسکائی لیب‘ کے گرنے کا بھی پیش آیا۔ اسکائی لیب دراصل ایک امریکی خلائی اسٹیشن تھا جو 1973ء میں خلاء میں بھیجا گیا تھا۔ جولائی 1980ء میں کسی خرابی کے باعث یہ زمین کی طرف گرنے لگا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا کہ کس حصے پر گر کر تباہی مچائے گا۔ ہر شخص ڈرا سہما گھوم رہا تھا۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور رسائل میں صرف اسی کے تذکرے تھے۔ لوگوں کی باہمی گفتگو کا موضوع بھی یہی تھا۔
مجھے یاد ہے کہ اس وقت ٹی وی کے کئی ڈراموں اور پروگراموں میں اسکائی لیب کا ذکر ہوتا رہا۔ گلوکارہ ریشماں نے اُنہی دنوں اپنے ایک انٹرویو میں کہا ’بھئی ہم نے تو اسکائی لیب کے گرنے سے پہلے ہی اپنے سارے پیسے کھا پی کر برابر کر دیے، مرنے کے بعد ان پیسوں کا کیا فائدہ‘۔ اسی طرح ایک ڈرامے میں کوئی شخص ٹانگے کے نیچے آکر زخمی ہوجاتا ہے تو دوسرا اس پر طنز کرتا ہے کہ ’ابے نیچے ہی آنا تھا تو اسکائی لیب کے نیچے آتا، کوئی خبر تو بنتی‘۔ خیر جناب 11 جولائی 1980ء کے دن بالآخر یہ اسکائی لیب آسٹریلیا کے قریب بحر ہند میں گر کر تباہ ہوگیا اور دنیا کو اس کے خوف سے نجات ملی۔

اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرا غیر نصابی مطالعہ بھی زور و شور سے جاری تھا۔ آٹھویں جماعت تک میں فیروز سنز کی کتابیں، اشتیاق احمد اور اے حمید کے ناول اور بچوں کے کئی رسالے باقاعدگی سے خریدتا رہا۔ ایڈگر رائس بروز کے ناول ’ٹارزن‘ کا بہترین اردو ترجمہ فیروز سنز نے 4 ضخیم حصوں میں چھاپا تھا۔ میں نے یہ چاروں حصے خریدے اور مسلسل 5 راتیں جاگ کر چاروں حصے پڑھ ڈالے۔ آخری حصہ ختم ہوتے ہوتے مجھے سخت بخار چڑھ آیا تھا۔
گلیور کے سفر، رابن سن کروسو، ہانز کرسچن اینڈرسن کی کہانیاں، لیڈی برڈ کی کتابیں اور دیگر غیر ملکی لٹریچر کے ترجمے کراچی کے ہر بک اسٹال پر خوب بکا کرتے تھے۔ عمران سیریز کی شہرت آسمان پر ہوا کرتی تھی۔ لوگ کتابوں کی دکانوں اور لائبریریوں میں ابن صفی، مظہر کلیم اور ایچ اقبال کی عمران سیریز و دیگر جاسوسی ناولوں کی ایڈوانس بکنگ کروایا کرتے تھے۔


کھوکھراپار میں بے شمار لائبریریاں تھیں جو شام کو کھلا کرتی تھیں۔ ایک ناول کا ایک دن کا کرایہ 50 پیسے ہوا کرتا تھا۔ چناچہ بڑے سے بڑے ناول کو بھی 24 گھنٹے میں مکمل کرلینے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ اگلے دن کا کرایہ نہ چڑھ جائے۔ کھوکھراپار کی سب سے معروف لائبریری کا نام ’آپ کی اپنی لائبریری‘ تھا جو ڈاکخانہ چوک کے قریب تھی۔ یہاں اکثر شام کو علاقے کے ادیب اور شاعر بھی جمع ہوا کرتے تھے۔ لائبریری کے مالک ہمیں ان سے متعارف کرواتے اور ہم ان سے مؤدبانہ مصافحہ کیا کرتے تھے۔
کتابوں کی اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بھی ایک شوق چرایا۔ بچوں کے رسالوں کا مکمل ریکارڈ جمع کرنے کا شوق۔ خصوصاً ماہنامہ ’ہمدرد نونہال کراچی‘ اور ماہنامہ ’تعلیم و تربیت لاہور‘ کا۔ میرا ریکارڈ 1975ء سے شروع ہوتا تھا۔ رسالے تو میرے پاس کئی جمع تھے لیکن اکثر سالوں کے پورے 12 شمارے مکمل نہ تھے۔ پہلے تو میں نے لیاقت مارکیٹ اور ملیر ٹنکی مارکیٹ کے سارے ردّی والے کباڑی چھان مارے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ تعلیم و تربیت کا دفتر ہی لاہور میں تھا، البتہ ہمدرد نونہال کا دفتر کراچی میں ناظم آباد میں تھا۔

ایک دن میں ہمدرد فاؤنڈیشن پہنچ گیا اور وہاں نونہال کے مدیر مسعود احمد برکاتی سے ملاقات ہوگئی۔ پرانے رسالے تو وہاں سے بہت کم ملے لیکن برکاتی صاحب کا دستِ شفقت مل گیا۔ اب میں اکثر ہمدرد فاؤنڈیشن کے چکر لگانے لگا۔ ایک دن برکاتی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ ہم پہلی منزل سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے اور ایک دروازہ کھول کر بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے ایک وسیع ٹیبل تھی جس کے دوسری طرف سفید شیروانی میں ملبوس ایک شخص بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔
میری نظر جیسے ہی ان کے چہرے پر پڑی میں سناٹے میں آگیا۔ یہ حکیم محمد سعید تھے، ہمارے رہبر، ہمارے استاد اور ہمارے آئیڈیل۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور سلام کیا۔ حکیم صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ برکاتی صاحب بھی برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ برکاتی صاحب نے میرا تعارف کروایا کہ ’حکیم صاحب یہ عبیداللہ ہیں، عبیداللہ سندھی۔ مگر ہیں اردو کے عاشق۔ نونہال کے نہ صرف قاری ہیں بلکہ اس سے شدید محبت کرتے ہیں‘۔
حکیم صاحب نے مجھ سے مل کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے آٹوگراف کے ساتھ ایک کتاب مجھے تحفے میں دی اور کہا ’میاں عبیداللہ، ڈائری لکھا کرو روزانہ۔ لکھتے رہو گے تو ایک دن بڑے ادیب بن جاؤ گے‘۔ میں نے ان کی نصیحت کو سینے سے لگالیا۔ ڈائری لکھتا رہا، کئی سال لکھتا رہا۔ ادیب بنا کہ نہیں، یہ تو میری تحریریں پڑھنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔
ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد نونہال، حکیم سعید اور برکاتی صاحب سے رشتہ کئی سال جاری رہا۔ میں نے بچوں کے لیے 1986ء میں سوات کا سفرنامہ لکھا تو برکاتی صاحب نے اسے نہ صرف نونہال میں اہتمام سے چھاپا بلکہ اس تحریر کا اس دور کے حساب سے معقول معاوضہ بھی دیا۔ 1989ء میں میری کھینچی ہوئی ایک تصویر کو ہمدرد نونہال کے ٹائٹل کی زینت بنایا اور مجھے اس تصویر کا بہت اچھا معاوضہ بھی دیا۔
وقت کی اہمیت اس دور میں بھی بہت تھی لیکن وہ جیب میں موبائل فون رکھنے کا نہیں بلکہ کلائی پر گھڑی باندھنے کا زمانہ تھا۔ کیسیو کی الیکٹرانک ڈیجیٹل گھڑیاں تو ابھی عام نہیں ہوئی تھیں البتہ گھنٹہ، منٹ اور تاریخ بتانے والی اور آٹومیٹک چابی والی نسبتاً ماڈرن گھڑیوں کا دور آچکا تھا۔ سیکو فائیو، سٹیزن، فاورلیوبا اور 17 جیولز والی سوئس گھڑیوں کا فیشن جاری تھا۔ لیکن ہم ابھی غریب تھے۔ گھڑی رکھنے کے بجائے راہگیروں سے ٹائم پوچھ کر گزارا کرتے تھے۔ کسی بھی راہ چلتے معزز شخص کو روک کر پوچھتے ’سنئے جناب، ٹائم کیا ہوا ہے؟‘ تو وہ بالکل ناراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ خوشی خوشی ٹائم بتا دیتا تھا۔ اس وقت ’جناب‘ کہنے کا رواج تھا، ’انکل‘ کہنے کا مرض ابھی عام نہیں ہوا تھا۔ آج کراچی میں کسی کو اس طرح اچانک روک کر ٹائم پوچھیں تو وہ خوفزدہ ہوکر اِدھر اُدھر دیکھنے لگے گا کہ ہم کہیں اس کا موبائل فون تو نہیں چھیننے والے۔
آٹھویں جماعت میں اسکول والے ہمیں موئنجو دڑو کی سیر کروانے لاڑکانہ لے گئے۔ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوا۔ میرے پاس گھڑی نہیں تھی۔ ایک کلاس فیلو جو ہمارے ساتھ نہیں جا رہا تھا اس نے اپنی نئی سیکو فائیو گھڑی مجھے ادھار دے دی۔ لاڑکانہ میں شام کے وقت سارے لڑکے ایک نہر پر گھومنے گئے۔ وہاں وہ گھڑی کہیں گر گئی۔ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں چلا لیکن نہر سے واپسی پر اس کا علم ہوا تو ایک کہرام مچ گیا۔
چند سو روپے کی گھڑی کا گم ہوجانا اس دور میں اتنا بڑا صدمہ تھا کہ جو شاید آج لوگوں کو 20 ہزار روپے کے موبائل فون کے گم ہونے پر بھی نہ ہوتا ہو اور پھر وہ گھڑی تو تھی بھی میری نہیں، دوست سے ادھار مانگ کر پہنی تھی اور اسے جا کر واپس کرنی تھی۔ میں نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ چنانچہ بڑی کلاس کے چند لڑکوں کا گروپ ٹارچیں ہاتھ میں لے کر رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ پھر اس نہر کی طرف چل پڑا کہ جہاں گھڑی کے پائے جانے کا امکان تھا۔
لڑکے وہاں پہنچ کر اِدھر اُدھر پھیل گئے اور زمین پر ٹارچ کی روشنی مار مار کر دیکھنے لگے۔ اچانک ایک لڑکے نے نعرہ بلند کیا۔ اسے ایک جھاڑی کے نیچے پڑی ہوئی گھڑی نظر آگئی تھی۔ سب اس کی طرف لپکے۔ میں نے آگے بڑھ کر گھڑی اٹھا لی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب کراچی واپس پہنچ کر پہلے ہی دن میں نے وہ گھڑی اپنے دوست کو واپس کردی۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد بالآخر میں نے بڑے بھائی کے ساتھ صدر جاکر 300 روپے کی ایک اومیکس تھری اسٹار گھڑی خرید ہی لی۔

ہمارے گھر میں ٹی وی آنے کا واقعہ یادگار تو تھا ہی، 80ء کے شروع میں ایک اور الیکٹرانک اپلائنس کا اضافہ ہوا۔ یہ نیشنل کا خوبصورت ڈبل ڈور جاپانی ریفریجریٹر تھا جس کے دروازے میں ٹھنڈے پانی کا ڈسپنسر بھی نصب تھا۔ یعنی فرج کا دروازہ کھولے بغیر ہی ہم اس کی ٹونٹی سے گلاس بھر کر ٹھنڈا ٹھار پانی پی سکتے تھے۔ یہ فرج امّی اور ابّا صدر وکٹوریہ روڈ (اب عبداللہ ہارون روڈ) کی الیکٹرانک مارکیٹ سے 7500 روپے میں لے کر آئے تھے۔ فرج کی خوشی میں ہم کئی دن نہال رہے اور اس میں آئسکریم جمانے کی کوششیں کرتے رہے۔ پھر حالات معمول پر آگئے۔
اس سال مجھ سے بڑے بھائی کی شادی ہوگئی۔ بھائی کی شادی کے بعد اب میرا ہی نمبر تھا اور اس بات کو عام طور پر ’فائل اوپر آجانا‘ کہا جاتا تھا۔ خیر میں اب تھا بھی ایک 14 سال کا کراچی برانڈ دبلا پتلا سانولا سلونا نوجوان۔ بھائی کی شادی میں گاؤں سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ ساتھ کراچی کے نئے تعلقات والے مہمانوں کا بھی ہفتہ بھر آنا جانا رہا۔
انہی جاننے والوں کے بچوں میں ایک اردو اسپیکنگ خاندان کی ایک گڑیا سی لڑکی بھی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی ہوگئی۔ ایک دن شام کو ہم دونوں باہر ایک دکان سے کوئی سودا لے کر آ رہے تھے۔ گلی میں سناٹا تھا۔ اچانک اس نے مجھ سے پوچھا:
’کیا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟‘
میں ٹھٹھک کر کھڑا ہوگیا اور بغیر کچھ بولے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔
’بولو نا بھئی۔ کیا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟‘ وہ پھر گویا ہوئی۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں شرارت بھرے تارے ٹمٹما رہے تھے۔ میں گڑبڑا سا گیا۔
’نن نہیں ۔۔۔ نہیں تو ۔۔۔‘ میرے منہ سے بس یہی نکلا۔
اس نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی:
’تو پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟‘








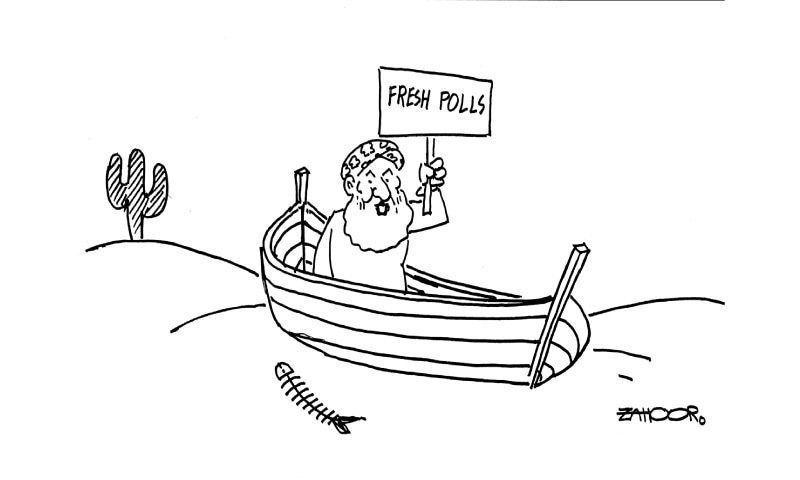
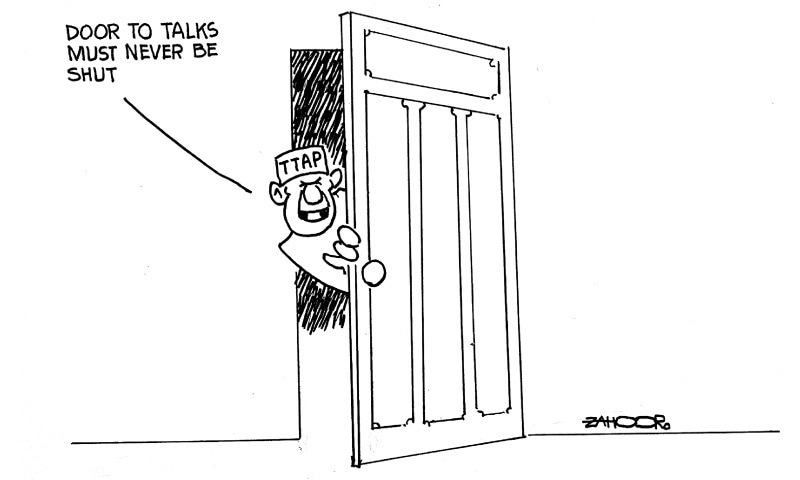





 لائیو ٹی وی
لائیو ٹی وی
تبصرے (12) بند ہیں