کراچی جو اِک شہر تھا (تیسرا حصہ)
یہ اس سیریز کا تیسرا بلاگ ہے۔ پہلا اور دوسرا حصہ پڑھیں۔
فلم اور فوٹوگرافی کی دنیا سے میرا پہلا تعارف پرائمری اسکول کے زمانے میں ہوا تھا۔ قائد آباد پر اس زمانے میں کچھ پھیری والے ایک بڑا سا لکڑی کا باکس پیٹھ پر لادے محلہ در محلہ گھومتے تھے۔ اس ڈبے کے اطراف میں بڑے بڑے محدب عدسے (شیشے کے لینس) لگے ہوتے تھے۔ بچے ایک آنہ دے کر ان کے اندر نظر آنے والی دنیا جہان کی رنگا رنگ تصویروں کا تماشہ دیکھتے تھے۔ اس تصویری شو کو ’سیربین‘ کہا جاتا تھا۔ میں نے بھی کئی مرتبہ یہ شو دیکھا۔
بی بی سی ریڈیو کے ایک پروگرام کا نام بھی سیربین ہوتا تھا، جو کہ آج بھی براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ قائد آباد اسٹاپ پر اور ماچس فیکٹری کے ساتھ والے فٹ پاتھ پر بھی اسی طرح کے لوگ بیٹھے ایک آنے میں ایک دوربین نما ویو ماسٹر (View Master) میں مکہ اور مدینہ کی تھری ڈی تصویریں دکھایا کرتے تھے۔

اس کے بعد منی مووی (Mini Movie) کا دور آیا۔ منی مووی چھوٹی سی ایک آنکھ والی دوربین ہوتی تھی جس میں چند منٹ کی کارٹون فلم چلتی تھی۔
منی مووی 4 آنے کی دکھائی جاتی تھی۔ ہم قائد آباد میں جہاں رہتے تھے وہاں آس پاس ایک یا 2 نہیں بلکہ پورے 4 سنیما گھر تھے، جن میں مہر سنیما، گلستان ٹاکیز، نرگس سنیما اور لالہ زار سنیما شامل تھے جہاں روزانہ 3 شوز ہوتے تھے۔ پہلا شو سہ پہر 3 سے 6، دوسرا شو شام 6 سے 9 اور تیسرا شو رات 9 سے 12 تک ہوتا تھا۔ اردو، پنجابی اور پشتو فلمیں چونکہ 3 گھنٹے کی ہی ہوتی تھیں اس لیے یہ شو بھی 3 گھنٹے کے ہی ہوتے تھے، البتہ وہ انگریزی فلمیں جو ڈیڑھ گھنٹے کی ہوتی تھیں، ان کے ’ڈبل پروگرام‘ چلتے تھے۔

انگریزی فلموں کے ناموں کے عجیب عجیب ترجمے کیے جاتے تھے اور ایک نہیں بلکہ دو، دو نام لکھے جاتے تھے، مثلاً ’چالاک حسینہ عرف لنگڑا شکاری‘ یا ’خونخوار درندے عرف ہوس کے پجاری‘ وغیرہ۔ کبھی کبھی فلم کا اعلان کرنے کے لیے ایک تانگہ بھی لاؤڈ اسپیکر اور پوسٹر کے ساتھ گلیوں میں چکر لگاتا تھا اور محلے کے بچے اس تانگے کے پیچھے پیچھے جلوس بنا کر چلتے تھے۔ آج رات چلنے والے شو کے لیے ’آجشبکو‘ لکھا جاتا تھا۔ جسے ہم ’آجش بکو‘ پڑھتے تھے۔
ہم نے کبھی باقاعدہ ٹکٹ لے کر کوئی فلم تو نہیں دیکھی، البتہ 14 اگست اور 23 مارچ کے قومی ایّام پر یہ چاروں سنیما اپنے دروازے کھول دیتے تھے اور بچوں اور بڑوں کا ایک غول بیابانی سنیماؤں کی طرف دوڑ لگا دیتا تھا۔ ان فری شوز میں پوری فیچر فلم دکھانے کے بجائے ’ٹوٹے‘ دکھائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے پاکستانی قومی ترانے کی فلم چلائی جاتی تھی، اس کے بعد کچھ فلمی و غیر فلمی قومی نغمے، پاکستان پر دستاویزی فلمیں اور کچھ بے ضرر فلمی سین دکھائے جاتے تھے۔

مذکورہ چاروں سنیماؤں کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ اپنے فری شو ایک ساتھ چلانے کے بجائے یکے بعد دیگرے پیش کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاروں سنیماؤں میں جانے کا موقع مل جاتا تھا۔ لیاقت آباد اور منگھوپیر روڈ کے محلّوں میں ٹی وی دیکھنے اور پھر قائد آباد کے سنیماؤں والے اِن فری شوز نے میرے ذہن کو بچپن میں ہی فلم ٹیکنیک اور فلم میکنگ کی طرف راغب کردیا۔
سب سے اولین چیز جو میں نے بنائی، وہ ماچس کی ڈبیا اور رنگ برنگے شیشوں کی کرچیوں سے بنایا گیا کیلیڈو اسکوپ Kaleidoscope تھا۔ رنگین شیشوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک ماچس کی ڈبیا میں ڈال کر اسے ایک طرف سفید کاغذ چپکا کر بند کردیا جاتا تھا اور دوسری طرف اس کے اندر جھانکنے کے لیے ایک باریک سوراخ کردیا جاتا تھا۔ ہر بار اس ڈبیا کو ہلا ہلا کر اور پھر اس کا رخ سورج کی جانب کرکے سوراخ پر آنکھ جما کر اندر جھانکا جاتا تو اس میں ٹوٹے شیشوں کی رنگا رنگی ہر بار ایک نیا اور انوکھا منظر تخلیق کرکے حیران کردیتی تھی۔
اس زمانے میں پاکستانی رسالوں میں ایک فلم پروجیکٹر کا اشتہار آیا کرتا تھا، جس کے ذریعے گھر کے اندر ہی سنیما بنانے کی خوشخبری دی جاتی تھی۔ یہ پروجیکٹر مع چند سو فٹ سلولائڈ فلم کے 25 روپے کا ہوتا تھا۔ چوتھی جماعت تک ہمیں والدین کی طرف سے بس اور لوکل ٹرین میں اکیلے سفر کرنے کی اجازت مل چکی تھی، چنانچہ ایک دن میں ڈینسو ہال پر کھوڑی گارڈن مارکیٹ سے وہ فلم پروجیکٹر خرید کر لایا اور گھر میں ابّا سے چھپا کر رکھ دیا۔ اب اسکول کے بعد میرا خاصا وقت اس پروجیکٹر کے ساتھ ایک اندھیرے کمرے میں گزرنے لگا۔
ہمارے ماموں وڈیرہ امام بخش نے جب ایک مرتبہ مجھے اس فلم پروجیکٹر میں مگن دیکھا تو افسوس سے سر ہلا کر بولے ’یہ دیکھو، ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوگیا ہے۔‘ لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ابّا کے سامنے میرے اس خطرناک راز کو فاش نہیں کیا۔ میرے اس شوق نے آگے چل کر میری زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے اور بالآخر ایک وقت آیا کہ میں پروفیشنل فوٹو گرافر اور ڈاکیومنٹری فلم میکر بن گیا۔

اُس عمر میں طرح طرح کی چیزیں جمع کرنے کا بھی شوق ہوا۔ سب سے پہلے میں نے سگریٹ کی خالی ڈبیاں جمع کرنا شروع کیں کیونکہ یہ آسانی سے اور بڑی تعداد میں ہاتھ لگ جاتی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آج کے مقابلے میں اُس زمانے میں لوگ بہت زیادہ سگریٹ پیا کرتے تھے۔ کے ٹو، ایمبیسی، بگلا، قینچی، ولز، ریڈ اینڈ وائٹ، گولڈ لیف، کیپسٹن، مارون گولڈ وغیرہ۔ ان ڈبیوں کے ڈیزائن اور ان سے اٹھنے والی تمباکو کی بھینی بھینی خوشبو مجھے آج تک اچھی طرح یاد ہے، لیکن سگریٹ کے سیکڑوں پیکٹ جمع کرنے کے باوجود آج تک ایک بھی سگریٹ نہیں پی۔ کئی سال بعد ڈاک ٹکٹ اور غیر ملکی سکے جمع کرنے کا بھی شوق ہوا اور ان کی ایک بڑی تعداد جمع کی۔

ریڈیو کالونی کے پرائمری اسکول میں مجھے جو کلاس فیلو ملے، ان میں محسن نامی لڑکا ایک یادگار کردار تھا۔ محسن اور اس کا بھائی منیر قائد آباد کے قبرستان سے ملحق کچی آبادی کے ایک غریب گھرانے سے پڑھنے آتے تھے۔ ان کے والد قائد آباد اسٹاپ پر غالباً بھنی ہوئی کلیجی کا ٹھیلا لگاتے تھے۔
محسن ہماری کلاس میں ہوتا تھا جبکہ اس کا بڑا بھائی منیر ہم سے ایک جماعت آگے تھا۔ سانولا سا محسن ہر وقت کھیل کود کے موڈ میں رہتا تھا۔ وہ فٹ بال کا دیوانہ تھا اور اکثر ایک خیالی فٹ بال کو ہوا میں لاتیں مارتا رہتا تھا۔ اس دوران وہ گنگناتا بھی رہتا تھا اور زیادہ تر محمد رفیع کا گانا، ’ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں‘ گاتا تھا، لیکن وہ اس گانے کو کچھ تبدیل کرکے کچھ یوں گاتا تھا:
’ہم کالے ہیں تو کیا ہوا؟ دل والے ہیں تو کیا ہوا؟‘
ٹھیک ہی گاتا تھا، کیونکہ اپنے حسبِ حال جو گاتا تھا۔ جب ہم پانچویں جماعت میں پہنچے تو محسن کا بھائی منیر پانچویں پاس کرگیا، لیکن اس کے ابّا نے اسے سیکنڈری اسکول میں داخل کروانے کے بجائے اپنے ٹھیلے پر لگا لیا، شاید وہ 2 بچوں کی پڑھائی کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے۔ محسن نے ہمارے ساتھ مارے باندھے کسی طرح پانچویں جماعت پوری تو کرلی، لیکن جب چھٹی جماعت کے لیے سیکنڈری اسکول میں داخلے کا وقت آیا تو اس کے ابّا نے اندازہ لگا لیا کہ محسن پڑھاکو بچہ نہیں، بلکہ منیر پڑھاکو بچہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے محسن کے بجائے منیر کو چھٹی جماعت میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا۔
یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوگیا، بڑے بھائی منیر کی پڑھائی میں چونکہ ایک سال کا وقفہ آچکا تھا اس لیے اس کے سیکنڈری اسکول داخلے میں رکاوٹ آسکتی تھی۔ چنانچہ دونوں بچوں کے نام راتوں رات بدل دیے گئے، محسن ’منیر‘ ہوگیا اور منیر ’محسن‘ بن گیا اور محسن کے پرائمری سرٹیفکیٹ پر منیر کا داخلہ ہمارے ساتھ چھٹی جماعت میں ہوگیا۔ سیکنڈری اسکول میں ہم جب بھی اسے منیر کے نام سے پکارتے، تو وہ فوراً گھبرا کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے ہمیں ’شش شش‘ کرکے خاموش کرواتا اور یاد دلاتا کہ اب وہ منیر نہیں، محسن ہے۔ چھوٹا بھائی محسن اب منیر کی جگہ ابّا کے ٹھیلے پر جانے لگا۔ ہم اکثر اس کے پاس سے گزرتے تو وہ ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلاتا اور سر جھکا کر کام کرتے ہوئے گنگنانے لگتا:
ہم کالے ہیں، تو کیا ہوا؟
دل والے ہیں ،تو کیا ہوا؟
پھر ایک ناصر بھی تھا، ناصر بلوچ۔ اس بیچارے کو اِملا نہیں آتا تھا۔ جب بھی اردو اِملا کی کلاس ہوتی، وہ ہم پڑھاکو بچوں میں گھس کر بیٹھ جاتا اور ہمارے لکھے گئے املا کی نقل کرتا۔ ہو بہو کاپی۔ ہم کوئی غلطی کرتے تو اسے کراس لگا کر ’کاٹم‘ کرتے تھے ٹھیک اسی طرح وہ بھی اس غلطی کو پہلے اچھی طرح دیکھ کر کاپی کرتا اور پھر اسے اہتمام سے کاٹ دیتا تھا۔ کئی سال پہلے کی آخری اطلاع کے مطابق ناصر گدھا گاڑی چلا رہا تھا۔ کیا خبر اب ٹرک چلاتا ہو۔
مجھ سے پہلے کلاس میں جو بچہ اول آتا تھا، وہ عارف تھا۔ ننھا منا دبلا پتلا منحنی سا بچہ، جو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ عارف سویڈش کالج سے منسلک قائد آباد میں رہتا تھا۔ میری اس سے فوراً دوستی ہوگئی تھی اور مزے کی بات یہ کہ کلاس میں پوزیشن کے مقابلے میں مجھ سے شکست کھانے کے باوجود اس کی مجھ سے دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔
میں جن ہم جماعت دوستوں کے گھر جاتا تھا، ان میں عارف بھی شامل تھا اور میں غالباً سب سے زیادہ اسی کے گھر جاتا تھا کیونکہ وہاں کتابیں ہوتیں تھیں۔ بچوں کے لیے مزیدار کہانیوں کی بے شمار کتابیں جو میں نہ صرف عارف کے گھر بیٹھ کر پڑھتا تھا بلکہ اپنے گھر بھی لاسکتا تھا۔ وہاں ’اردو ڈائجسٹ‘ بھی آتا تھا اور میں اس کی بھی ورق گردانی کرتا تھا۔ اردو تحریروں سے دلچسپی کا آغاز عارف کے گھر سے ہی ہوا۔ وہاں ہمارے لیے ایک دلچسپی اور بھی تھی، عارف کی امّی ہر جمعے کی شام بچوں کا ایک اصلاحی پروگرام کرتی تھیں، جس میں کہانیاں، اچھی اچھی باتیں اور چند حدیثیں سنانے کے بعد سب بچوں کو مزے مزے کی کھانے کی چیزیں بھی دی جاتی تھیں۔ اس محلے میں رہنے والے ہماری کلاس کے کئی بچے جمعے کی اس محفل میں آتے تھے۔ میں ان میں واحد بچہ تھا کہ جو اس محلے کا بھی نہیں تھا اور اردو بولنے والا بھی نہیں تھا، بلکہ پیپلز پارٹی کے حامی سندھی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ عارف کی شفیق والدہ نے اس حوالے سے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی البتہ عارف کی چھوٹی بہن فوزیہ، جو بھٹو کے بہت خلاف تھی، مجھے سخت ناپسند کرتی تھی کہ یہ ’پیپلا‘ ہمارے گھر کیوں آتا ہے؟
اسکول میں تو ہمیں کہانیاں اور نظمیں صرف اردو کی پہلی کتاب، اردو کی دوسری کتاب، اردو کی تیسری کتاب وغیرہ میں ہی پڑھنے کو ملتی تھیں، لیکن مجھ میں اردو مطالعے کا شوق اس سے کہیں زیادہ پیدا ہوگیا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے کباڑیوں کے ٹھیلوں سے بچوں کے پرانے رسالے خریدنے شروع کیے۔ ہمدرد نونہال، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، ہونہار، نوبہار وغیرہ۔ کباڑی ایک پرانا رسالہ چونیّ (یعنی چار آنے یا پچیس پیسے) کا دیتا تھا۔ ایک روپے کے چار رسالے۔
پھر گھر میں خوشحالی آئی تو میں ہر ماہ قائد آباد بس اسٹاپ پر کتابوں کی معروف دکان ’ہاشمی کتاب گھر‘ سے ڈیڑھ روپیہ دے کر نئے رسالے بھی خریدنے لگا۔ رسالوں کے علاوہ فیروز سنز کے شائع کردہ بچوں کے ناول، داستانِ امیر حمزہ، عمرو عیار کی طلسمِ ہوش رُبا، الف لیلہ، گل بکاؤلی، طوطا کہانی، قصہ چہار درویش وغیرہ، پھر ہمدرد فاؤنڈیشن کی کہانیاں، اشتیاق احمد کی ’انسپکٹر جمشید، محمود، فاروق، فرزانہ‘ سیریز کے جاسوسی ناول اور اے حمید کی ’عنبر ماریا ناگ‘ سیریز بھی خریدنے لگا۔ ہاشمی کتاب گھر غالباً آج بھی قائد آباد میں موجود ہے۔
کباڑی سے خریدنے والے رسالوں میں رفتہ رفتہ اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، سب رنگ، خواتین ڈائجسٹ، پاکیزہ، جاسوسی اور سسپنس ڈائجسٹ بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ خواتین کے رسالے زینب باجی اور ہاجرہ باجی کے لیے آتے تھے۔ الطاف حسن قریشی، شکیل عادل زادہ، ابنِ انشاء، مقبول جہانگیر، قاسم محمود، مستنصر حسین تارڑ، اشفاق احمد، بانو قدسیہ اور ممتاز مفتی کی شخصیات اور تحریروں سے ہم نئے نئے واقف ہونا شروع ہوئے تھے۔ محمود شام کا رسالہ ’فاتح‘ پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی باقاعدگی سے آتا تھا۔
چھٹی جماعت میں میرا داخلہ ملیر کالا بورڈ میں گورنمنٹ آصف بوائز سیکنڈری اسکول میں ہوگیا اور یہ میرے لیے پھر ایک نئی دنیا تھی۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت ملیر سعود آباد کے رہنے والے اردو بولنے والے گھرانوں سے آتی تھی اور یہ سارے بچے بڑے تمیز دار، با اخلاق اور فوراً دوست بن جانے والے تھے۔ میری دوستیوں کا دائرہ اور وسیع ہوگیا۔ پڑھائی میں اپنی بہتر کارکردگی کے باعث میں یہاں بھی کلاس کا نمایاں بچہ بن گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں یہاں بھی کلاس مانیٹر بن گیا۔ اس وقت تک میں اتنا ’اُردو‘ ہوچکا تھا کہ مجھے کوئی بھی سندھی نہیں سمجھتا تھا، میرے سندھی زبان کے جوہر صرف سندھی سبجیکٹ میں سامنے آتے تھے۔
ہم قائد آباد سے کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن (کے ٹی سی) کی بسوں میں یا لانڈھی اسٹیشن سے لوکل ٹرین میں بیٹھ کر اسکول جاتے تھے۔ کے ٹی سی کی بسوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے صرف 30 پیسے کا ٹکٹ ہوتا تھا، خواہ کہیں بھی جائیں۔ ہمارے اسکول سے کالج اور یونیورسٹی کے دور تک طلباء کا ٹکٹ یہی 30 پیسے رہا، حتیٰ کہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہی ختم ہوگئی۔

پانچویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے شہر میں ایک بار پھر فسادات پھوٹ پڑے۔ یہ سال 1977ء تھا اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کا سال تھا۔ قائد آباد میں فساد تو کوئی نہیں ہوا، البتہ کرفیو کا دائرہ وسیع ہوتے ہوئے یہاں تک بھی آ پہنچا تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک سندھی گھرانہ تھا اور پیپلز پارٹی کا حامی تھا۔ جئے بھٹو سدا جئے کا نعرہ ہمارے ہونٹوں پر مچلتا رہتا تھا اور امّی کے ہاتھ کا سیا ہوا پیپلز پارٹی کا سہ رنگا جھنڈا ایک 20 فٹ بلند موٹے بانس پر بندھا ہمارے گھر کی چھت پر لہراتا تھا۔
قائد آباد میں رہنے والوں کی اکثریت ‘نَو ستارے‘ یعنی پاکستان قومی اتحاد کی حامی تھی اور ان کی طرف سے ابّا کو دھمکیاں بھی موصول ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن اب ہم قائد آباد کے پرانے رہائشی ہوچکے تھے، ابّا کا حلقہ دوستاں بھی خاصا وسیع ہوچکا تھا، اس لیے ہم بلاخوف و خطر رہتے رہے۔ 77ء کے انتخابات میں قائد آباد کا علاقہ پیپلز پارٹی کے امیدوار حفیظ پیرزادہ کے حلقے میں شامل تھا۔ مجھے یاد ہے کہ حفیظ پیرزادہ کا جلسہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہوا تھا۔ میں اس میں پیپلز پارٹی کا ایک چھوٹا سا جھنڈا ہاتھ میں لہراتا ہوا شریک ہوا تھا۔ یہ جھنڈا بھی مجھے امّی نے سی کردیا تھا۔ اس جلسے میں جس وقت ’جئے بھٹو، سدا جئے‘ کے نعرے لگ رہے ہوتے، تو اسی وقت جلسے کے باہر ’بھٹو کے سر پہ ہل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا‘ کے نعرے بھی گونجتے رہتے، لیکن کوئی تصادم نہیں ہوا۔ ’ہل‘ پاکستان قومی اتحاد کا انتخابی نشان تھا۔
کچھ دن بعد جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ اُلٹ دیا۔ اس کی پہلی تقریر ٹی وی سے نشر ہوئی جو ہم نے مین روڈ پر تاجی جنرل اسٹور کے باہر رکھے ٹیلی ویژن سیٹ پر ایک ہجوم کے ساتھ کھڑے ہوکر دیکھی۔ قائد آباد کی بھٹو مخالف آبادی میں ایک پُرمسرت جوش تھا، لیکن ہمارا گھر سوگوار تھا۔ محلے کے پٹھان اور ہزاروی بچے ہمیں آتا جاتا دیکھ کر طنزیہ ہنستے اور خواہ مخواہ بھٹو کے خلاف نعرہ لگاتے۔ اب ابّا یہاں بھی بے چین رہنے لگے۔
قائد آباد میں ابّا کی ٹیلرنگ شاپ خوب چل نکلی تھی اور ان چند سالوں میں امّی نے ہزاروں روپے پس انداز کرلیے تھے۔ لیکن ابّا پھر سے غائب رہنے لگے۔ وہ اکثر ملیر کھوکھراپار کے چکر لگاتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک ’کیہر‘ کمیونٹی دریافت کرلی تھی۔ کھوکھرا پار کی یہ کمیونٹی تھی تو ہماری ہم قوم، لیکن وہ سندھ کے نہیں بلکہ انڈیا کے علاقے کَچھ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اور دیگر کچھی برادریاں سعود آباد سے آگے ملیر توسیعی کالونی کے آخری بلاکس میں رہتی تھیں۔
یہ علاقہ بھی بہت پُرامن تھا کیونکہ وہاں سب محنت کش اور غریب لوگ تھے۔ مرد زیادہ تر کراچی پورٹ پر مختلف کام کرتے تھے اور عورتیں پی ای سی ایچ ایس کے بنگلوں میں ’کام والیاں‘ ہوا کرتی تھیں۔ کام والیوں کو اس وقت تک ’ماسی‘ کہنے کا رواج نہیں پڑا تھا۔ ابّا کی دوستیاں کھوکھرا پار کی کیہر کمیونٹی میں بڑھتی گئیں اور بالآخر انہوں نے وہاں ایک 100 گز کا پرانا مکان لے کر اسے نئے سرے سے تعمیر کروا لیا۔
1978ء میں ہم قائد آباد چھوڑ کر کھوکھرا پار کے اس مکان میں منتقل ہوگئے۔ یہاں سے میرا اسکول بھی قریب تھا۔ پہلے تو میں کے ٹی سی کی 15A روٹ کی بس میں یا لی مارکیٹ سے آنے والی پرائیویٹ بسوں میں آتا جاتا رہا۔ پھر ابّا نے اپنی پرانی ہرکولیس سائیکل مجھے دے دی اور خود پیکو کمپنی کی نئی سائیکل خرید لی، میں اب سائیکل پر اسکول جانے لگا۔
آصف بوائز سیکنڈری اسکول ایک دوپہر کی شفٹ والا اسکول تھا۔ صبح یہ آصف گرلز سیکنڈری اسکول ہوتا تھا اور دوپہر میں ہمیں اس وقت تک اسکول کے گیٹ پر کھڑا رہنا پڑتا تھا جب تک صبح والی شفٹ کی آخری لڑکی اسکول سے باہر نہ نکل جائے۔ نیلی قمیض اور سفید شلوار کے یونیفارم میں اٹھلاتی کھل کھلاتی سیکڑوں لڑکیوں کے اس غول کو اسکول سے برآمد ہوتے دیکھنا ہم نوخیز لڑکوں کے لیے بڑا دلکش نظارہ ہوا کرتا تھا۔ اس منظر کی لگن اکثر لڑکوں کو وقت سے پہلے ہی اسکول کی طرف کھینچ لاتی تھی۔








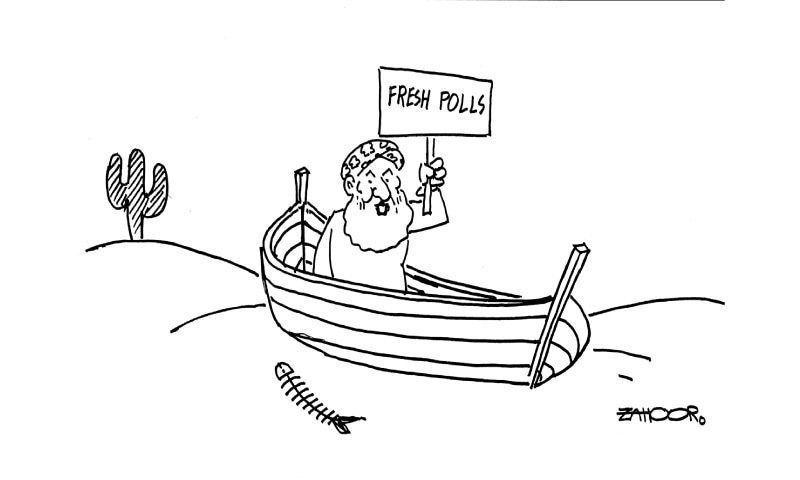
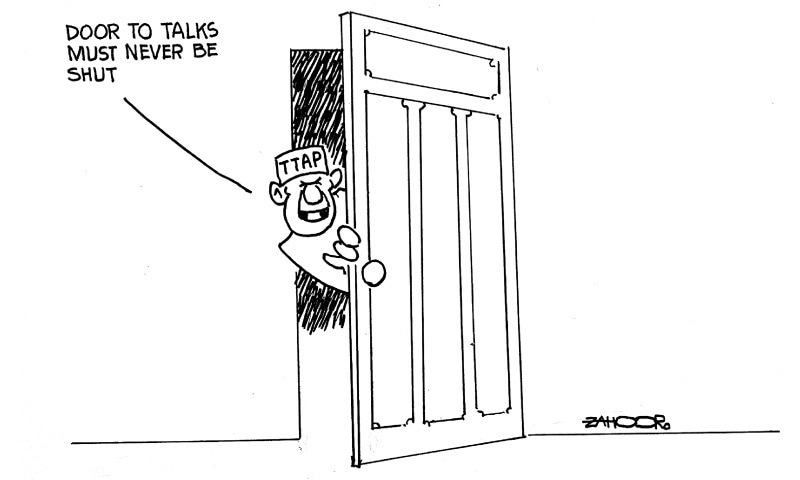





 لائیو ٹی وی
لائیو ٹی وی
تبصرے (16) بند ہیں